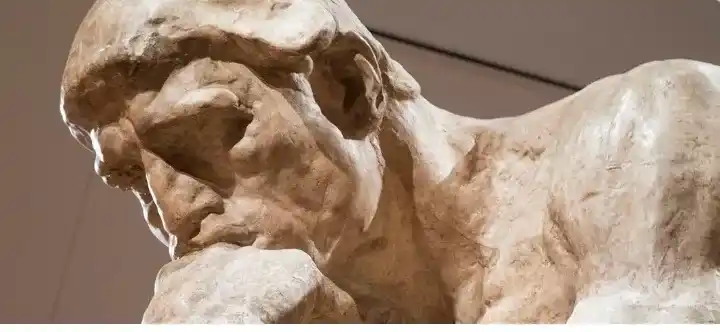وسط اسی کی دہائی میں سرکاری نوکری کے دوران والد صاحب کا تبادلہ جب گوجرہ شہر ہوا تو ہماری عمر یہی کوئی آٹھ یا نو برس ہوگی۔ تیسری سےچوتھی جماعت میں ترقی پائی ہی تھی کہ ایک اجنبی شہر کے اجنبی سکول میں داخل ہونا پڑ گیا، سکول کی بابت کہانی پھر کبھی سہی کہ فی الوقت اس تمہید کا مقصد کچھ اور ہے۔
گوجرہ میں ہم چونکہ سرکاری آفیسرز کالونی میں رہائش پذیر تھے لہٰذا عام گلی محلوں میں رہنے کا کچھ خاص تجربہ نہیں تھا، یہیں اسی کالونی میں والدصاحب کے اکثر جونئیر ملازمین بھی رہائش پذیر ہوا کرتے۔ یہہں ہمیں ایک نیا شوق پیدا ہوگیا، ہوتا یوں کہ سکول کے بعد والد صاحب کا کوئی جونئیر ملازم اپنے گھر کے باہر سرکاری بائی سائیکل پارک کر کے کسی کام گھر جاتا تو ہم اسکے بائی سائیکل کا بغور معائنہ شروع کر دیتے۔ بائ سائیکل کے بریکس دبا کر دیکھنا یا کھڑے سائیکل کے پیڈل پر زور دے کر دیکھنا کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے؟ اور پھر آہستہ آہستہ ترقی کرتے بائی سائیکل کو ہینڈل سے پکڑ کر آٹھ دس فٹ آگے پیچھے کر لینا۔
ہم چونکہ شروع سے ہی ہونہار واقع ہوئے تھے سو یوں ہی کرتے کرتے اللہ کے فضل و کرم اور والدین کی دعاؤں کے بعد اپنی انتھک محنت اورگونا گوں صلاحیتوں کی بناء پر شریکوں کے سینوں پر مونگ دلتے ہوئے ہم قینچی سائیکل چلانا سیکھ گئے۔ ہمارے ممی ڈیڈی طبیعت یا برگر قارئین شاید قینچی سائیکل چلانے کی ٹیکنالوجی سے ناواقف ہونگے تو کچھ تفصیل بیان کئیے دیتے ہیں۔ وطن عزیز میں عام سہراب بائی سائیکل کا فریم 22انچ کا ہوتا ہے اوراس سے آٹھ دس انچ کی بلندی پر بائی سائیکل کی کاک پٹ یعنی سیٹ عرف کاٹھی۔ اگر بائی سائیکل پائلٹ کا قد کاٹھی سے کم ہو تو لازمی بات ہے کہ بائی سائیکل پر سواری کی صورت پائلٹ کے پاؤں پیڈلز تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ برصغیر کے عوامی سائیسدانوں نے اسکا حل قینچی سائیکل ٹیکنیک کی صورت نکالا ہے یہاں ہم مغرب سے یوں سبقت لے گئے کہ گورا آج کی تاریخ تک اس ٹیکنیک سے ناواقف ہے۔ اس ٹیکنیک میں بائی سائیکل کا پائلٹ چلتے بائی سائیکل کے پیڈل پر کھڑا ہو کر عین جب اسکا سر ہینڈل سے بمشکل چند انچ اوپر ہوتا ہے اپنی دوسری ٹانگ فریم کے اندر سے گزار کر دوسری طرف کےپیڈل پر زور دیتے ایک یوگا آسن کی شکل اختیار کرتے ہوئے سائیکل کو ڈرائیو کرلیتا ہے۔
بہرحال، ایک دن والد صاحب نے کہیں ہمیں بائی سایکل پر یونہی ٹیسٹ فلائٹ کرتے ہوئے دیکھ لیا تو ہمارے شوق، لگن اور محنت پر اظہارِ اعتماد کرتے ہوئےہمیں ایک عدد سولہ انچ فریم کا نسبتاً چھوٹا بائی سائیکل جسے عرفِ عام میں ‘سائیکلی‘ کہا جاتا ہے، لے دیا۔
اب یہ سائیکلی اس دور میں ہمارا کُل اثاثہ ہوا کرتی۔ سائیکلی پر سکول جانا، ایم سی ہائی سکول کے گراونڈز میں استاد روڈے کی ہاکی ٹیم کی پریکٹس گیم دیکھنے جانا ہو یا چاچے مند کی برفی لانا ہو یا حسبِ قد ایک یا دو ہم عمروں کو لفث دینا، یہاں تک کہ گھر کا چھوٹا موٹا سودا سلف بھی اسی سائیکلی پر ہی لانا۔جب سے ہم سائیکلی پر سودا سلف لانے کے قابل ہوئے تھے ہماری والدہ کو ہم پر خاص فخر محسوس ہونے لگا تھا، ہم خود بھی اب خود کو گھر کا ایک کارآمد فرد تصور کرنے لگے تھے۔
گوجرہ میں ہمارا سکول ‘گورنمنٹ مڈل سکول شہر کے تقریباً وسط میں واقع ہوا کرتا تھا اور اسکے مرکزی دروازے کے بالکل سامنے سڑک کے اس پار بوائیز کالج واقعہ ہے۔ سکول اور کالج کے درمیان جو سڑک ہے اس دور میں اس سڑک پر سرکاری ہسپتال ہوا کرتا تھا اور اس سے متصل چند ایک دوکانیں اور میڈیکل سٹورز وغیرہ۔ انہی دوکانوں سے ذرا ہٹ کر کریانے کی ایک کچی یعنی گارے مٹی سے بنی دوکان ہوا کرتی تھی اور ایک باریش اور پنج وقتہ نمازی دوکاندار اسکے پروپرائیٹر ہوا کرتے۔ اس نسبت سے ہم بچوں میں یہ ‘مولوی دی دوکان‘ کے نام سے مشہور تھی اور ہم بچوں کی ضروریات جیسے نائٹ رائڈر چورن،ریمبو املی، مےفئیر ببل گم، مچلز ٹافی وغیرہ یہیں سے پوری ہوتیں۔ گھر کا سودا سلف بھی اسی ‘مولوی دی دوکان‘ سے آتا۔
ایسے ہی ایک نومبر کی سہانی صبح جب سکول سے چھٹی تھی، ہمیں والدہ صاحبہ نے دس روپے دے کر مولوی کی دوکان سے مسور کی دال لینے بھیجا، دس روپے کی قدر اس دور میں یوں سمجھ لیں کہ ان دنوں ابو کے یاماہا موٹر سائیکل میں پیٹرول آٹھ روپے لیٹر کی شرح سے ڈلا کرتا تھا۔ ہم نے اپنی نائٹ رائیڈر یعنی سائیکلی نکالی اور خود کو مائیکل نائٹ تصور کرتے ہوئے منہ سے کِٹ کی تقلید میں وُوووو وُوووو کی آوازیں نکالتے ہوئے لہراتے ہوئے “مولوی دی دوکان‘ کی طرف گامزن ہوگئے، دوکان کے قریب پہنچے تو احساس ہوا کہ بوائیز کالج کے دروازے سے ذرا پہلے کسی نے ایک دو قناتیں وغیرہ لگا کر میز اوردو چار کرسیاں رکھی ہوئی ہیں اور لاؤڈ سپیکر پر رننگ کمنٹری جاری ہے۔ جیسے ہی ذرا اور قریب پہنچے تو دو باریش نوجوان بازو اور پیر پھیلائےاچانک زقند لگا کر سڑک کے بیچ میں آ کودے، انکا شکار ہم تھے۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے دیہات میں شام کو مرغیاں ڈربے میں بند کرنے کیلئیے گھیری جاتیں ہیں۔
یہ اسلامی جمعیت طلبہ کا کیمپ تھا، سچ پوچھیں تو ہمیں ان دنوں طلبہ سیاست تو درکنار بنیادی سیاست کی بھی سمجھ بوجھ نہیں تھی۔ بس اتنا معلوم تھا کہ صدر جنرل محمد ضیاالحق ہیں اور ہر تقریر سے پہلے نحمدہ و نصلی علی پڑھتے ہیں۔ سکول جاتے ہوئے اکثر جمعیت طلبہ اسلام اور اسلامی جمیت طلبہ کے کیمپ لگے دیکھتے لیکن ان کیمپوں کے اصل مقاصد سمجھنے کی کبھی زحمت گوارا نہ کی۔ ہمیں ان دنوں وہی اچھا لگتا جو سب سے زیادہ فری سٹیکرز دیتا۔ ان دنوں وطن عزیز کو کشمیر میں بھارتی ظلم و ستم اور کشمیر کے پاکستان کی شہ رگ ہونے کا احساس ہونے میں ابھی چند برس باقی تھے، لہذا اس قسم کی طلبہ تنظیموں کے کیمپوں پر فقط مسئلہء فلسطین ہی جاگزیں ہوتا۔ ہم ہمیشہ اسی حیرت میں مبتلا رہتے کہ دونوں طلبہ تنظیمیں ہمیں ایک دوسرے کی حمایت کرنے سے کیوں روکتی ہیں؟ حالانکہ دونوں تنظیموں کا بنیادی مقصد ایک یعنی اسلام کی ترویج اور فلسطین کی آزادی ہے۔ یہ تو بہت بعد میں جا کر معلوم پڑا کہ انکا تو آپس میں اِٹ کتے کا ویر ہے۔
بہرحال ہمیں مرغوں کی طرح گھیرنے والے نصراللہ بھائی اور خورشید بھائی تھے، یہ نام بھی ہمیں بعد میں پتہ چلے۔ نصراللہ بھائی نے ہماری نائٹ رائیڈر کا ہینڈل تھام لیا اور خورشید بھائی نے نہایت اخلاق سے بتایا کہ بوائز کالج میں کچھ دیر کیلئیے چلنا ہوگا وہاں فلسطین پر اسرائیل کے مظالم بارے فلم دیکھائی جائے گی۔ ہم نے پوچھا کیا کالج میں سینما بھی ہے؟ نصراللہ بھائی نے بتایا کہ نہیں وی سی آر پر دیکھائی جائے گی۔ ہمارے گھر میں لفظ وی سی آر ایک لفظِ ممنوع تھا۔ فلم وغیرہ دیکھنا تو درکنار وی سی آر کا ذکر بھی والد صاحب کے سامنے ممنوع تھا لہٰذا قدرتی طور پر مسئلہ فلسطین سےزیادہ لفظ وی سی آر ہماری توجہ کا مرکز ٹھہرا۔ سوچا کہ مولوی کی دوکان بھاگی تھوڑی جا رہی ہے؟ فلم دیکھ کر واپس آ کر مسور کی دال خرید لیں گے۔
کالج کے ایک لیکچر ہال میں ایک بیس انچ کے رنگین ٹی وی کا اہتمام تھا، کچھ دیر میں نصراللہ بھائی اور خورشید بھائی اور انکا رفقاء کی مرغے گھیرنے کی مشق سے بیس پچیس لوگ جمع ہو گئے تو فلم شروع ہو گئی۔ فلم میں وہی ظلم و ستم دیکھایا گیا تھا جو آج کے دن تک جاری ہے۔ فلم دیکھتے ہوئے جذباتی مناظر بھی سامنے آئے۔ فلم میں مسلسل گنبدِ صخرہ کو مسجدِ اقصیٰ بتایا جاتا رہا اور اسکی آزادی کو مسلمانوں کا اولین مقصد قرار دی گیا تھا۔ مجھے یہ ماننے میں قطعاً کوئی عار نہیں کہ اس دن مجھے پہلی بار حقیقتاً فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم سے آگاہی ہوئی۔ دل بہت بوجھل تھا، فلم کے دوران نصراللہ بھائی کبھی کبھار پورے جوش سے حلق پھاڑ قسم کے نعرے بلند کرتے۔۔‘الحذر الحذر‘۔۔ اور حاضرین جواب دیتے ‘انتقام انتقام‘، ‘اسرائیل کی گرتی ہوئی دیواروں کو‘۔۔۔اور حاضرین فلک شگاف جواب دیتے ‘ایک دھکا اور دو‘ ۔۔فلسطین کی آزادی تک، جنگ رہے گی جنگ رہے گی۔۔ وغیرہ ۔فلم کے اختتام پر خورشید بھائی نے ایک نہایت مؤثر اور جذبات سے بھرپور تقریر کی جس میں فلسطین کیلئیے جانی اور مالی امداد کا اعادہ کیا گیا تھا۔ تقریر کے اختتام پر تمام حاضرینِ محفل سے فلسطین کی امداد کی خصوصی استدعا کی گئی، سب نے حسب توفیق کچھ نہ کچھ دیا۔ میری جیب میں مسور کی دال کے دس روپے تھے وہ میں نے فوری طور پر عطیہ کر دئیے، میں جب گھر کا سودا سلف لاتا تو بقیہ پیسوں کی ریزگاری امی ہمیشہ مجھے دے دیا کرتیں، میرے پاس ریزگاری میں وہ بھی اڑھائی روپے تھے، سو میں نے وہ بھی دان کر دئیے۔ نم آنکھوں اور بوجھل دل کے ساتھ لیکچر ہال سے باہر نکلا تو دیکھ کر پاؤں تل سے زمین نکل گئی کہ میری نائٹ رائیڈر غائب تھی۔ کسی مومن بھائی کو شاید فلسطین پہنچنے کی زیادہ جلدی تھی اور وہ میری سائیکلی لے کر نکل گیا۔ پیدل گھر پہنچا تو امی سے کافی ‘خاطر تواضع‘ ہوئی, مسور کی دال خریدنے کیلئیے دوبارہ پیسے دئیے، اس دفعہ ہم سیدھے مولوی کی دوکان پر گئے اور سیدھے مسور کی دال لے کر واپس آ گئے۔ بہرحال یہ ضرور تھا کہ دل پر کوئی بوجھ نہیں تھا، امی آج بھی اکثر میرے اس کارنامے کا تذکرہ کیا کرتی ہیں۔
یہ واقعہ آج سے کوئی اڑتیس سال پرانا ہے، ایک نسل جوانی گزار کر عمر کے اگلے سفر کی طرف گامزن ہو چکی اور اسکی جگہ ایک اور نسل لے چکی، اڑتیس سال قبل الحذر الحذر انتقام انتقام کے نعروں کے درمیان جو رقومات جمع کی جاتی تھیں ان میں سے آج تک کتنی حقیقی حقداروں تک پہنچیں؟ کسی کو معلوم نہیں۔ لیکن نہ فلسطینیوں پر مظالم میں کمی آئی نہ اسرائیل کی گرتی ہوئی دیواروں کو اور دھکا دیا جا سکا۔ دھکا دینے کیلئیے پیسے جمع کرنیوالوں کی نسلیں البتہ اسرائیل کے زیر سایہ چلنے والے اداروں میں ضرور پائی گئیں۔
ایسے چندے جمع کرنیوالوں سے یہ گذارش کرنا تھی کہ ہم نے چالیس سال صبر کر لیا، اگر دیواروں کو دھکا وغیرہ دینے کا ارادہ بدل گیا ہو تو برائےمہربانی ہمارے ساڑھے بارہ روپے واپس کر دیں۔